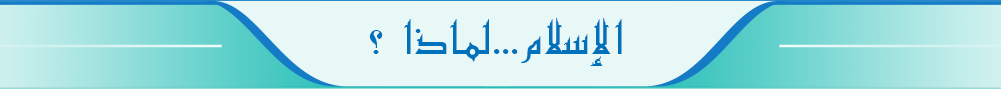| اسلام میں سیاست | خون اور نجات کا فریب: امریکی و اسرائیلی تعلقات کی مذہبی بنیادین

خون اور نجات کا فریب: امریکی و اسرائیلی تعلقات کی مذہبی بنیادین
شیخ مصطفیٰ الحجری
مشہور مزاحیہ فلمی سلسلے "آسٹن پاورز" میں دو منفی کردار پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر ایول ہے جو اصل مخالف اور شر کا مجسمہ ہے، اور دوسرا اُس کا چھوٹا مگر مکمل ہم شکل ساتھی منی می ہے۔ان دونوں کرداروں کو علامتی نظر سے دیکھا جائے تو یہ ہماری معاصر دنیا میں امریکہ اور غاصب صہیونی ریاست (اسرائیل) کے باہمی تعلق کی ایک بلیغ تمثیل کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ دونوں طاقتیں اپنی فکری بنیادوں، مذہبی تعبیرات، اور تاریخی شعور میں گہری مماثلت رکھتی ہیں۔ ان کے سیاسی طرزِ عمل، دوسروں کے ساتھ رویّے، اور سماجی و معاشی سرگرمیوں کی ساخت بھی حیران کن حد تک ایک جیسی ہے۔ گویا کہ ایک بڑی قوت ہے جو منصوبہ بندی کرتی ہے، اور دوسری اُس کے خاکے کو عملی شکل دیتی ہے۔
یہ سلسلہ اُس وقت شروع ہوا جب پیورٹنز (یعنی مذہبی طور پر سخت گیر پروٹسٹنٹ) اپنی کشتیوں پر سوار ہو کر یورپ سے ہجرت کر کے "نئی دنیا" یعنی امریکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اُن کے نزدیک یہ نئی دنیا دراصل ارضِ موعود تھی ایک مقدّس خطہ، جہاں وہ اپنے مذہبی تصورِ نجات کو عملی شکل دے سکتے تھے۔ ان کی یہ ہجرت اُس زمانے کے یورپ کی سیاسی، مذہبی اور سماجی گھٹن سے نجات حاصل کرنے کی ایک سعی تھی۔ پیورٹنز دراصل پروٹسٹنٹ اصلاحی تحریک کے اندر اُبھرنے والا ایک انتہا پسند مذہبی گروہ تھے، جو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ کلیسائے انگلستان نے ابھی تک کیتھولک کلیسا سے مکمل علیحدگی اختیار نہیں کی۔ ان کے نزدیک انگریزی چرچ میں اب بھی کیتھولک عبادات کے اثرات، جیسے رسومات، تصویریں، مجسمے اور گرجا گھروں کی تزئین و آرائش برقرار تھے، جو اُن کے نزدیک حقیقی ایمان کے منافی تھے۔ چنانچہ وہ اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ مسیحی عبادت کو ان تمام "بدعات" اور غیر کتابی عناصر سے پاک کیا جائے، کیونکہ نہ تو عہدِ قدیم (Old Testament) میں اور نہ ہی عہدِ جدید (New Testament) میں ان کا کوئی ذکر یا جواز ملتا ہے۔ ان کے نزدیک ایمان کا جوہر سادگی، تقویٰ، اور براہِ راست تعلقِ الٰہی میں پوشیدہ تھا، نہ کہ رسوم و ظواہر میں۔
درحقیقت، بائبل کے مطابق ایک مثالی ریاست کے قیام کی آرزو ہی وہ اصل محرک تھی جس نے پیورٹنز کو ہجرت پر آمادہ کیا۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے "اپنی مثالی بستی" جسے وہ محبت سے "نئی صہیون" (New Zion) کہا کرتے تھے، تعمیر کرنے کی کوشش کی، تاکہ وہ مسیحی سلف کے نقشِ قدم پر ایک پاکیزہ اور الہٰی معاشرہ تشکیل دے سکیں۔
یہ سلفی یا متطہّر تصورِ ایمان بعد ازاں بھی امریکی اجتماعی شعور میں گہرائی سے پیوست رہا، اور اس کے اثرات انیسویں صدی تک واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے عکس امریکی ادب و فنون میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے ، مثلاً ایمیلی ڈِکنسن کی شاعری میں روحانی خلوت اور نجات کا تصور، اور والٹ وِٹمین کے اشعار میں نئے انسان اور نئی دنیا کا خواب۔وِٹمین اپنے دور کے یورپی نژاد مہاجرین اور نومولود امریکی شہریوں کو یہ پیغام دیتا تھا کہ وہ یورپی تہذیب کے بوجھ اور اس کی فکری زنجیروں کو اتار پھینکیں، اور "ارضِ عذراء" یعنی نئی امریکی سرزمین پر ایک نئی ابتدا کریں، گویا وہ انہیں دعوت دے رہا تھا کہ وہ فردوسِ زمینی، یعنی امریکی مثالی دنیا، کو ازسرِنو آباد کریں۔
امریکہ کے اس فردوسی تصور کا دائرہ محض ادیبوں اور شاعروں تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی زندہ اور فعّال تصوراتی قوت ہے جو امریکی روزمرّہ زندگی اور ثقافتی شعور میں بھی گہرائی سے رچی بسی ہے۔ امریکی ٹیلی وژن کے پروگراموں میں ہم بارہا یہ علامتی تفریق دیکھتے ہیں کہ منفی یا شرپسند کردار اکثر کسی یورپی نام کے حامل ہوتے ہیں، مثلاً فابریزی یا بیلگارڈ ، جب کہ نیک، معصوم یا منصف کردار عام طور پر اینجلوسیکسن (Anglo-Saxon) نام رکھتے ہیں، جیسے جون یا سمِتھ۔
یہی فکری بنیاد اور سلفی ذہنیت ہمیں اُن یہودی قیادتوں کے ہاں بھی دکھائی دیتی ہے جنہوں نے غاصب صہیونی ریاست (اسرائیل) کی بنیاد رکھی۔ ان یہودیوں نے بھی منتشر زندگی یعنی "الشتات" کے تصور کو سختی سے رد کیا۔ صہیونی نظریے کے مطابق، کسی غیر یہودی تہذیب یا قوم کے اندر یہودی وجود کا برقرار رہنا ایک غیر فطری اور روحانی طور پر بیمار حالت ہے۔ اسی لیے وہ بھی ماضی کے اُس موہوم سنہری دور کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب یہودی ایک خالص اور خودمختار قومی وجود کے طور پر زندہ تھے، اور ان پر ابھی تک تاریخ کی غیر یہودی آمیزشوں یا "شوائب" کا سایہ نہیں پڑا تھا۔ یہی وہ مقدّس ماضی کا فریب ہے جو صہیونی منصوبے اور امریکی فردوس کے تصور، دونوں کی فکری جڑوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔
اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر یہودی مہاجرین، جو فلسطین کی طرف گئے، نے اپنے اصل نام ترک کرکے انہیں قدیم عبرانی ناموں میں تبدیل کرلیا۔ یہ علامتی تبدیلی دراصل اُس ذہنی و روحانی رجعت کی مظہر ہے جو "خالص آغاز" اور "الہٰی نسب" کی طرف واپسی کی آرزو سے پیدا ہوتی ہے۔ درحقیقت، آباء و اجداد کی پاکیزہ زندگی (جو زمانے کی آمیزشوں، اخلاقی انحرافات اور غیر قوموں کی عادات سے مبرا سمجھی جاتی ہے) کا یہ تصور، امریکی اور یہودی دونوں وجدانوں پر گہرے طور پر حاوی ہے۔ یہ وہی نفسیاتی اور مذہبی رجحان ہے جو ماضی کے مقدّس زمانے کو حال کی نجات کا ماخذ قرار دیتا ہے۔ شاید یہی وہ نکتہ ہے جو اس بات کی توضیح کرتا ہے کہ بیشتر صہیونی اور اسرائیلی مفکرین اپنی ریاست کو صرف ایک سیاسی یا قومی ادارہ نہیں سمجھتے، بلکہ ایک ماورائی وجود کے طور پر دیکھتے ہیں ایک ایسی تجسیم جو عہدِ نامہ قدیم کی نبوّتوں کی تکمیل کے طور پر ظاہر ہوئی۔
جیسا کہ نیویارک ٹائمز کے ایک مدیر نے نہایت بصیرت کے ساتھ لکھا تھا:
"اگر کوئی شخص اسرائیل کی خارجہ پالیسی کو سمجھنا چاہتا ہے تو اُسے( کتابِ اشعیا )کا مکمل مطالعہ کرنا ہوگا؛ کیونکہ ارضِ اسرائیل کا توسیعی تصور، یا گریٹر اسرائیل کا خواب (مصر کے دریا سے لے کر دریائے فرات تک کے علاقوں پر محیط ہے ) دراصل ایک مذہبی و عقیدتی نظریہ ہے، جس کا تعلق نہ جغرافیے سے ہے، نہ زمانے سے۔
یہی تصور دراصل پیورٹنز کے امریکہ میں اپنی مثالی بستی کے خواب کا عین نمونہ ہے۔ وہ پورے یقین کے ساتھ سمجھتے تھے کہ اُن کی یورپ سے امریکہ ہجرت محض جغرافیائی تبدیلی نہیں بلکہ ایک بڑے مشن کا حصہ ہے۔ اُن کے عقیدے کے مطابق، وہ اس لیے روانہ ہوئے تاکہ "پہاڑی پر شہر" (City upon a Hill) تعمیر کریں، ایک ایسی مثالی بستی جسے تمام اقوام دیکھیں، اس کے طور و عمل کی پیروی کریں، اور یوں بھلائی عام ہو اور نجاتِ انسانی کا وعدہ پورا ہو جائے۔ پیورٹنز کے نزدیک یہ نظریہ خالصتاً مذہبی اور تقدیسی تصور تھا۔ ان کے فہمِ دین میں دنیا کی ہر شے ایک علامت تھی خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک اشاریہ، جس کے ذریعے وہ اپنے اخلاقی و روحانی استدلال کو تقویت دیتے تھے۔
جس طرح اسرائیلی صہیونی تحریک نے اپنے توسیعی اقدامات کے لیے مذہبی علامات کو جواز کے طور پر استعمال کیا، بالکل اسی طرح پیورٹنز نے بھی انہی "مذہبی علامتوں' کا سہارا لے کر اپنی تمام جارحانہ سرگرمیوں خواہ وہ امریکی براعظم کے مقامی باشندوں (ریڈ انڈینز) کی نسل کشی ہو یا دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کو دینی رنگ میں پیش کیا۔ یہ مذہبی خواب اور قومی توسیع پسندی کا باہمی امتزاج صرف ابتدائی ادوار تک محدود نہ رہا بلکہ انیسویں صدی تک امریکی ذہن اور سیاست پر گہرے اثرات مرتب کرتا رہا۔ مثلاً والٹ وِٹمین، جو امریکی رومانوی شعور کا ایک مرکزی شاعر تھا، میکسیکو سمیت دیگر ممالک میں امریکی فتوحات کو اسی ایمان کے ساتھ دیکھتا تھا جس طرح ایک مومن کسی "الہٰی راز"پر ایمان رکھتا ہے۔ اُس کا خواب "عظیم امریکہ" تھا، ایک ایسی سلطنت جو کینیڈا سے لے کر کیوبا تک، اور قطبِ شمالی سے خطِ استوا تک پھیلی ہو۔ وہ اس توسیعی خواب کو نہایت رومانی انداز میں "میری لطیف رؤیا" کہا کرتا تھا۔
اسی طرح امریکی مفکر جان او’سلیوان نے انیسویں صدی میں اس استعمار پسندانہ رجحان کو "القدر الجلي"کا نام دیا ، یعنی یہ عقیدہ کہ امریکہ کو خدائی مشن کے تحت زمین پر اپنا اقتدار پھیلانا مقدّر ہے۔
یہی مذہبی جواز بیسویں صدی میں بھی مختلف صورتوں میں زندہ رہا۔ مثال کے طور پر کارڈینل سِلمن نے ویتنام جنگ کے دوران امریکی فوجیوں کو "مسیح کے سپاہی" قرار دیا، جبکہ ایک امریکی جنرل نے ایک مکمّل ویتنامی گاؤں کو تباہ کرنے کے بعد نہایت سادگی سے یہ کہا کہ "ہمیں اسے تباہ کرنا پڑا تاکہ اسے بچایا جا سکے"
یہ امریکی جنرل دراصل اُس اسرائیلی فوجی ذہنیت کا ہم شکل ہے جو اپنے اندر یہ احساس رکھتی ہے کہ وہ کسی خاص مشن کا حامل ہے ، گویا خود اسے اس کام کی انجام دہی کے لیے چُن لیا ہے۔ اسی احساسِ "اختیار"کے تحت وہ بدترین مظالم کا ارتکاب کرتا ہے، اور پھر بھی اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں آتا، نہ اس کی آنکھ میں شرم یا تاسّف کی کوئی لرزش دکھائی دیتی ہے۔
جس طرح پیورٹنز نے جب امریکہ کی سرزمین پر قبضہ کیا تو وہاں اپنی بالادستی کو زرعی و عسکری نوآبادیات کے قیام کے ذریعے مستحکم کیا، اسی طرزِ عمل کو بعد میں غاصب صہیونی آبادکاروں نے بھی اپنایا۔ انہوں نے فلسطین پر قبضہ اسی حکمتِ عملی کے تحت کیا یعنی زراعت اور عسکریت کے امتزاج سے منظم بستیاں قائم کر کے زمین پر بتدریج قبضہ جمانا۔
یوں پیورٹنز اور صہیونیوں دونوں کے طرزِ فکر اور طرزِ عمل میں ایک مشترک استعمار پسندانہ منطق کارفرما ہے: مذہبی تقدیس کے لبادے میں زمین، طاقت اور نجات کے خواب کو حقیقت کا روپ دینا۔
امریکی اور صہیونی وجدان کو جو ذہنیت سمت دیتی ہے، اس کی بنیاد فکر و اخلاق پر عمل کی ترجیح ہے۔ یہ وہی رویّہ ہے جسے انگریزی میں "کاؤبائے ذہنیت"کہا جاتا ہے ، یعنی ایسا شخص جو غور و تدبّر کے بجائے فوری ردِعمل، تیز فیصلہ، اور عمل کی سرعت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ ذہنیت امریکی ثقافت کا مرکزی استعارہ بن چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صہیونی ناظرین امریکی فلموں کے ان کاؤبائے ہیروز کو دیوانگی کی حد تک پسند کرتے ہیں۔ ان فلمی کرداروں میں ہمیشہ ایک ہی سانچہ دکھائی دیتا ہے کہ ہیرو اپنے حریف پر محض چند لمحوں کی برتری سے قابو پاتا ہے، وہ بروقت گولی چلانے کی مہارت سے فتح حاصل کرتا ہے، پھر بندوق کی نالی کو اطمینان سے پونچھتا ہے، اور اپنی محبوبہ کو بوسہ دے کر اپنی "فتح" کا جشن مناتا ہے۔ یہ منظر گویا عمل کی برتری، جذباتی ہیجان، اور اخلاقی تأمل کی نفی کی علامت بن چکا ہے۔
اسی ذہنی ساخت کی بازگشت اسرائیلی ادب اور داستانوں میں بھی سنائی دیتی ہے۔ ایک اسرائیلی کردار فخریہ کہتا ہے کہ "میں اپنے دشمنوں کو اس لیے ذبح نہیں کرتا کہ میں روسی نژاد یہودی ہوں یا فرانسیسی یہودی؛ میں انہیں اس لیے مارتا ہوں کہ میں ایک خالص یہودی ہوں، یہی میری آرزو ہے۔ مماثلتوں میں سب سے بنیادی پہلو شاید امریکائی اور صہیونی (اسرائیلی) وجدانوں میں نسلی بنیادوں پر مبنی تشدد ہے۔ ان کے نزدیک اُن کا مطلوبہ "فردوسِ زمینی" تبھی حقیقت بن سکتا ہے جب مقامی باشندوں (مقامی امریکی، ریڈ انڈینز) یا فلسطینیوں کو نکال دیا جائے یا ان کی آبادی کو ختم کر دیا جائے۔
یہ کوئی محض اتفاق نہیں کہ نعروں میں بھی ایک مشترکہ طرزِ فکر نظر آتا ہے؛ دونوں گروہوں نے مقبول نعرہ " أرض بلا شعب وشعب بلا أرض" (ایک ایسی زمین جس میں قوم نہ ہو، اور ایک ایسی قوم جس کے پاس زمین نہ ہو) بروئےِ کار لایا۔ مزید برآں، یہی وجہ ہے کہ ان معاشروں کو اکثر نسل پرستانہ خیالات اور رویّوں کے حامل سمجھا جاتا ہے، اور یہ خصوصیت اُن کے سیاسی و سماجی تعاملات میں باقاعدہ طور پر دکھائی دیتی ہے۔
یہ بات نہایت معنی خیز اور دلچسپ ہے کہ امریکی جمہوریت کے بانیوں نے، آزادی کے اعلان کے بعد، عبرانی زبان کو ریاست کی سرکاری زبان بنانے پر سنجیدگی سے غور کیا۔ ان کے نزدیک، چونکہ یہ نئی ریاست دراصل "صہیونِ جدید"کی تعبیر تھی، اس لیے عبرانی، جو قدیم بنی اسرائیل کی زبان سمجھی جاتی ہے ، اس روحانی نسبت کے لیے موزوں ترین علامت تھی۔ تاہم، کچھ عملی اور سیاسی ملاحظات کے باعث اس منصوبے سے دستبرداری اختیار کر لی گئی، اور انگریزی زبان ہی کو ریاست کی سرکاری زبان کے طور پر برقرار رکھا گیا۔ پھر بھی، یہ واقعہ اس امر کی گہری علامت ہے کہ امریکی قومی شعور کی تشکیل میں صہیونی اور عبرانی تصورات کی جڑیں کتنی گہری پیوست تھیں۔
بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اس نوع کی مماثلت محض ایک دلچسپ اتفاق ہے، جسے سنجیدگی سے نہیں لیا جا سکتا؛ کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان معاشی، جغرافیائی، اور تاریخی لحاظ سے نمایاں فرق موجود ہیں۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے۔ تاہم، اس کے باوجود ہمیں ان عام اسباق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں امریکی تہذیب کی ارتقائی تاریخ کے مطالعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت مسلّم ہے کہ امریکی تہذیب آج بھی کسی نہ کسی درجے میں پیورٹن اوہام اور اساطیر سے متاثر ہے، باوجود اس کے کہ کئی صدیاں گزر چکی ہیں اور معاشرتی و اقتصادی حالات میں بے شمار اور ہمہ گیر تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ گویا، زمانے کے تغیّر کے باوجود، نجات، برگزیدگی، اور فردوسِ ارضی کے وہی قدیم مذہبی تصورات اب بھی امریکی اجتماعی شعور کی تہہ میں سانس لے رہے ہیں۔
امریکی تہذیب کے بیشتر مؤرخین اور خصوصاً ان میں ممتاز مفکر پیری مِلر (Perry Miller)، جنہیں اس میدان کا بانی اور "امریکی فکری روایت کا معمارِ اوّل" سمجھا جاتا ہے ، اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ امریکی تہذیب کا حقیقی فہم پیورٹن وجدان کی گہری تفہیم کے بغیر ممکن نہیں۔
ان مؤرخین کے نزدیک، اگر کوئی شخص امریکی تمدّن کا مطالعہ پیورٹن فکر، اخلاقیات اور روحانیت کے تاریخی پس منظر سے الگ کرکے کرے، تو اس کی تحقیق ناگزیر طور پر ادھوری، سطحی اور بے روح رہے گی۔ کیونکہ امریکی تہذیب کی جو بنیاد، جوہر اور داخلی روح ہے، وہ دراصل اسی ابتدائی دینی و فکری قالب سے تشکیل پائی جو سب سے پہلے پیورٹنز نے وضع کیا تھا، ایک ایسا قالب جس نے امریکی معاشرت، سیاست اور حتیٰ کہ اس کے وجدانِ قومی کی سمت کا تعیّن کیا۔ اگر واقعی صورتِ حال ایسی ہی ہے، تو یہ کہنا بےجا نہ ہوگا کہ جھوٹے اور اسطوریاتی تصورات انسانی شعور اور رویّے پر گہرا اور دیرپا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ تصورات، باوجود اس کے کہ ان کی بنیاد حقیقت پر نہیں ہوتی، وقت کی دھول میں گم نہیں ہوتے؛ بلکہ وہ تاریخ کے مختلف ادوار میں نئی صورتوں اور نئے عنوانات کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، اور نسل در نسل انسانی وجدان کو اپنے حصار میں جکڑے رکھتے ہیں۔
یہی امر ہمیں اس تلخ نتیجے تک پہنچاتا ہے کہ یہودی قوم کے بارے میں ضرورت سے زیادہ رجائیت (Optimism) اختیار کرنا حقیقت پسندی نہیں۔ یہ قوم اب بھی اسرائیلی اساطیر کے جال میں اسیر ہے ، ایک ایسی ذہنی و روحانی غلامی میں مبتلا جو اسے اپنے ماضی کی خیالی نجاتی داستانوں کا پابند بناے ہوئے ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب تک وہ ان خود ساختہ اسطوری تصورات کے شکنجے سے نجات حاصل نہیں کرتی، تب تک وہ اپنی فکری و اخلاقی آزادی بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی لیے یہ توقع رکھنا خام خیالی ہوگی کہ ایک یا دو فتوحات ہی اسرائیلی وجود کو متزلزل کر دیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایک طویل، تلخ اور ہمہ گیر معرکے کے لیے تیار رہنا ہوگا ، خواہ وہ عسکری میدان میں ہو یا تہذیبی و فکری سطح پر، کیونکہ اسرائیلی انسان اپنی صہیونی، خیالی اور نجاتی اوہام سے اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے تاریخی اسطوری شعور سے حقیقی معنوں میں نجات حاصل نہ کرے۔
اسی طرح، ہمیں یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکی عوام کے لیے اسرائیلی ذہنیت کو سمجھنا اور اس سے ہمدردی رکھنا کوئی دشوار امر نہیں۔ اس کی وجہ دونوں اقوام کے وجدان اور فکری تشکیل میں پائی جانے والی وہ گہری مماثلت ہے ، ایک ایسی مماثلت جو نسلی برتری، تشدد، اور اخلاقی استثناء کے تصورات پر استوار ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی شعور ایک ہی اسطوری منبع سے سیراب ہوتے رہے ہیں، چاہے ان کی جغرافیائی اور تاریخی سمتیں بظاہر مختلف کیوں نہ ہوں۔