
| اسلام میں سیاست | عصرِ حضور اور غیبتِ معصومؑ میں شیعہ مکتبِ فکرمیں حکومت کا تصور
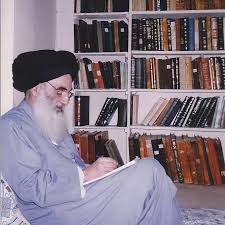
عصرِ حضور اور غیبتِ معصومؑ میں شیعہ مکتبِ فکرمیں حکومت کا تصور
شيخ معتصم السيد أحمد
اسلام محض عقائد یا مذہبی رسومات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایک جامع نظامِ حیات ہے جو انسانی وجود کے تمام پہلوؤں کو منظم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ نظام نہ صرف سماجی، اقتصادی اور سیاسی تعلقات کو ترتیب دیتا ہے بلکہ ایسے نظام تشکیل دینے کی بھی ترغیب دیتا ہے جو معاشرے میں عدل و استحکام کو یقینی بنائیں۔اسلام کے وضع کردہ اصول ایسے آفاقی اور قابلِ تطبیق ہیں جو ہر زمان و مکان کی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کسی مخصوص، غیر لچک دار سیاسی ڈھانچے پر اصرار نہیں کرتا، بلکہ وہ مختلف ادوار اور حالات کے مطابق ان کے ایسے حل پیش کرتا ہے جو اس کی بنیادی اقدار سے ہم آہنگ ہوں۔ ان حالات میں ایک اہم مرحلہ امام مہدیؑ کی غیبت کا ہے،کہ جب امت کووہ براہِ راست قیادت میسر نہیں رہی جو اس کے انتظامی اور سیاسی امور کی نگرانی کرتی تھی۔
اس تناظر میں جو اہم مسائل زیرِ بحث آتے ہیں، ان میں ایک مسئلہ "شیعہ مکتب فکر میں امامت اور اسلامی ریاست کے قیام میں امامت کا مقام" بھی ہے۔ شیعہ فکر میں امامت محض دنیاوی حکمرانی یا سیاسی منصب کا نام نہیں، بلکہ یہ اس الہٰی پیغام کا تسلسل ہے جس کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔امامت شیعی نظریے میں ایک جامع قیادت کا درجہ رکھتی ہے جو دین، معاشرت، معیشت، سیاست اور اخلاقیات کے تمام پہلوؤں کی نگہبانی کرتی ہے۔ امام کا وجود امت کے لیے ہدایت اور استقامت کا مرکز ہوتا ہے۔ لیکن امام مہدیؑ کی غیبت کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں امت کی دینی اور سیاسی رہنمائی کیسے ممکن ہے؟ یہی نکتہ اس بات کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے کہ امامت کے مفہوم کو وسیع تر انداز میں سمجھا جائے اور اس دور میں مرجعیت کے کردار کو اس سیاق میں ازسرِ نو دیکھا جائے۔
اسلام امتِ مسلمہ کو کچھ بنیادی اصول و ضوابط فراہم کرتا ہے، جن میں عدل، شوریٰ، حقوق کا تحفظ، اور اختیارات کی عادلانہ تقسیم جیسے تصورات نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ اصول، اسلامی معاشرے میں عدل و استحکام کے قیام کے لیے ایک فکری اور عملی بنیاد فراہم کرتے ہیں، اور انہی اصولوں کو اسلامی نظامِ حکومت اور اجتماعی پالیسی سازی کی رہنمائی کے لیے معیار بنایا جانا چاہیے۔یہ جامع اصول کسی ایک جامد ماڈل یا ناقابلِ تغیر سیاسی نظام پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ ان کی فطرت میں ایک وسعت، لچک اور مطابقت کی صلاحیت موجود ہے، جو امت کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے مخصوص حالات کے پیشِ نظر مختلف طرز ہائے حکومت اور انتظامی ڈھانچے مرتب کرے، بشرطیکہ وہ اسلامی اصولوں کے دائرے میں ہوں۔ اسی لیے یہ بات نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ سیاسی نظم و نسق کی تشکیل میں اہلِ خرد، اہلِ علم، اور تجربہ کار افراد پر مشتمل مشاورتی عمل کو بروئے کار لایا جائے، تاکہ وقت کی ضروریات، معاشرتی تغیرات، اور عالمی حالات کو مدِنظر رکھتے ہوئے ایسے سیاسی و انتظامی نظام وضع کیے جا سکیں جو زمانے کی ضروریات اور اس کے تغیرات سے ہم آہنگ ہوں۔
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دینی مرجعیت کے کردار کو نظرانداز کر دیا جائے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دورِ غیبت میں مرجعیت کی اہمیت اور ضرورت دوچند ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ امامت کے فکری و عملی تسلسل اور احکامِ شریعت کے نفاذ و تحفّظ کی ضامن ہوتی ہے۔ مرجعیت، اسلامی معاشرے میں دینی شعور، فکری رہنمائی، اور شرعی ہدایت کے ذریعے ایک فعال اور کلیدی کردار ادا کرتی ہے، اس کی یہ خصوصیت امت کے مختلف انفرادی و اجتماعی پہلوؤں میں اسلامی اقدار کی پاسداری کو تقویت دیتی ہے۔مرجعیت نہ صرف دینی فتاویٰ کا ماخذ ہے بلکہ یہ امت کی فکری بیداری، تہذیبی استقامت، اور اخلاقی تحفظ کا محور بھی ہے۔ تاہم، مرجعیت کے دائرۂ کار اور اس کے اختیارات کے بارے میں اہلِ فکر و فقہاء کے درمیان مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض نظریات کے مطابق، مرجعیت کا کردار سیاسی قیادت کو بھی شامل کرتا ہے، جیسا کہ "نظریۂ ولایتِ فقیہ" میں واضح کیا گیا ہے، جہاں فقیہ جامع الشرائط کو ریاستی نظم و نسق کا مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے، اور وہ نہ صرف دینی رہنمائی بلکہ سیاسی قیادت کا بھی مرکز ہوتا ہے۔دوسری جانب، کچھ اہلِ نظر کا موقف یہ ہے کہ مرجعیت کا کردار بالعموم احکامِ شرعیہ کے بیان، امورِ حسبہ، اور دینی و سماجی معاملات کی نگرانی تک محدود ہے، اور وہ ریاستی اختیارات یا حکومتی فیصلوں میں براہِ راست مداخلت کی حقدار نہیں سمجھی جاتی۔ اس فکری تنوع کے باعث ہمیں عملی دنیا میں مرجعیت اور سیاسی نظام کے مابین مختلف النوع تعلقات کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں، خصوصاً ان ممالک میں جہاں اکثریت شیعہ مکتبِ فکر سے وابستہ ہے۔
یہ فکری اختلاف درحقیقت شیعہ اجتہادی روایت کی وسعتِ نظر اور اسلامی فکر کی اس فطری لچک کا مظہر ہے، جو مختلف حالات و زمانوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اجتہادی تنوع، نہ صرف رائے کے اختلاف کو قبول کرتا ہے بلکہ اس کی روشنی میں ایسے متعدد امکانات جنم لیتے ہیں جو امتِ مسلمہ کو مختلف تاریخی مراحل میں درپیش چیلنجز کے مطابق ایک موزوں، مؤثر اور قابلِ عمل نظام کی تشکیل کی اجازت دیتے ہیں۔یہ فکری لچک اس امر کی بھی ضامن ہے کہ امت اپنے سیاسی اور سماجی ارتقاء کے مراحل میں کسی ایک متعین قالب میں محدود نہ ہو، بلکہ وہ ایسے اجتہادی اور فکری طریقِ کار اختیار کرے جو ایک طرف اسلامی اصولوں، جیسے عدل، شوریٰ، حفظِ حقوق، اور استقلالِ شریعت کی پاسداری کرے، اور دوسری جانب عصرِ حاضر کے پیچیدہ تقاضوں اور تیز رفتار تبدیلیوں کا جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔
اسلامی نظامِ حکومت اس بات کا ہرگز تقاضا نہیں کرتا کہ لازماً حکمران کوئی عالمِ دین ہی ہو، بلکہ اسلام کی فکری وسعت اور اس کے عملی حکمتِ عملی میں یہ امر شامل ہے کہ حکمرانی اُن افراد کے سپرد کی جائے جو عقلانی، تجرباتی، اور عملی معیاروں پر پورا اُترتے ہوں—یعنی جن کے اندر ریاستی نظم و نسق کو سنبھالنے، معاشرتی فلاح کو یقینی بنانے، اور سیاسی و معاشی استحکام قائم رکھنے کی صلاحیت موجود ہو۔اسلام ایک ہمہ گیر دین ہونے کے ناطے، انسانی معاشرے کی ہمہ جہت ضروریات کو تسلیم کرتا ہے، اور اسی لیے ریاست کے مختلف شعبہ جات میں ماہرینِ فن، اہلِ تدبیر، اور تجربہ کار افراد کی خدمات سے استفادے کو جائز اور ضروری قرار دیتا ہے۔ فقہِ اسلامی میں اس امر کی وسعت پائی جاتی ہے کہ کسی بھی ذمہ داری کی تفویض میں اہلیت، تخصص، اور مصلحتِ عامہ کو بنیادی معیار بنایا جائے۔تاہم، ان تمام تخصصات کی رہنمائی اسلامی اقدار کے ذریعے ہونی چا ہے، جو ان کے لیے ایک اخلاقی و اصولی سمت کا تعین کرتی ہیں۔
مثال کے طور پر جب ہم ایرانی ماڈل پر گفتگو کرتے ہیں، جو کہ موجودہ عہد میں ایک منفرد اور نمایاں تجربہ سمجھا جاتا ہے، تو لازم ہے کہ اس ماڈل کو ہرگز ایک مطلق نمونہ یا قابلِ تقلید فارمولہ نہ سمجھا جائے جسے بلا تفریق ہر ملک اور ہر معاشرے پر منطبق کیا جا سکتا ہو۔ ایرانی نظامِ حکومت مخصوص تاریخی، سماجی، تہذیبی اور فکری عوامل کے امتزاج کا نتیجہ ہے—ایسے عوامل جن کا جمع ہونا دیگر معاشروں میں بآسانی ممکن نہیں ہوتا۔چنانچہ اصل توجہ اس امر پر ہونی چاہیے کہ ہر اسلامی معاشرہ اپنی مخصوص تاریخ، ثقافت، اور چیلنجز کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسے ادارہ جاتی و انتظامی ڈھانچے وضع کرے جو نہ صرف شریعت کے اصولوں سے ہم آہنگ ہوں بلکہ عملی طور پر کامیاب اور پائیدار بھی ہوں۔ یہی وہ بنیادی قاعدہ ہے جو اسلام کو ایک "جامد نظام" کے بجائے ایک "متحرک منہجِ زندگی" میں تبدیل کرتا ہے، جو ہر دور اور ہر مقام پر اپنے نفاذ کی صلاحیت رکھتا ہے—بشرطیکہ اصولی بنیادوں پر اجتہادی بصیرت کے ساتھ اس کی تطبیق کی جائے۔
اسی تناظر میں یہ امر بھی روزِ روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں "مرجعیتِ دینی" کو کسی ایک معین یا جامد ماڈل کی تقلید تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے ایک لچکدار اور اجتہادی ذریعہ فہم کے طور پر دیکھا جانا چاہیے—ایسا وسیلہ یا ذریعہ جو نہ صرف اصولی راہنمائی فراہم کرتا ہے بلکہ مختلف سیاق و سباق میں متنوع سیاسی و انتظامی لائحہ عمل مرتب کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔عصرِ غیبتِ امام مہدی علیہ السلام میں یہ حقیقت اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے کہ اسلامی ریاست کا تصور کسی واحد سیاسی نظام یا ڈھانچے سے وابستہ نہیں ہے۔ شریعتِ اسلامی کی اعلیٰ قدریں—جیسے عدل، مساوات، شفافیت، اور خدمتِ عامہ—ہی وہ معیارات ہیں جن کی بنیاد پر مختلف ریاستی ماڈلز تشکیل پا سکتے ہیں۔ امت کو اس بات کی آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے اجتماعی شعور، عقلِ عملی، اور اجتہادی بصیرت کی بنیاد پر ایسے ماڈلز کا انتخاب کرے جو ان کے تاریخی، سماجی اور جغرافیائی حالات سے ہم آہنگ ہوں، ساتھ اسلامی اقدار کے ساتھ موافقت بھی رکھتے ہوں۔
اسی بنیاد پر یہ حقیقت بخوبی نمایاں ہو جاتی ہے کہ غیبتِ امام مہدی علیہ السلام کے دوران "اسلامی شہری ریاست کا تصور، شیعی فکر کے اساسی عقائد سے نہ صرف ہم آہنگ ہے بلکہ درحقیقت شریعتِ اسلامی کے ان اصولوں کا تسلسل ہے جو زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ، لچکدار اور مؤثر سیاسی و انتظامی نظامات کے قیام کی راہ ہموار کرتے ہیں—بشرطیکہ یہ نظامات ثقافتِ انتظار سے متصادم نہ ہوں، بلکہ اسی کے دائرے میں رہ کر تشکیل پائیں۔انتظار کی یہ ثقافت، جو شیعہ مسلمان اپنے دینی شعور کا حصہ بنائے ہوئے ہیں، ایک متحرک اور فعّال طرزِ فکر ہے جو عمل، اصلاح، اور اسلامی بنیادوں پر تعمیر و ترقی کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ امت کو اپنے سماجی و سیاسی حالات کی بہتری میں بھرپور شرکت کی دعوت دیتی ہے، جبکہ اہلِ ایمان کی نگاہیں اس تابناک مستقبل پر مرکوز رہتی ہیں جس میں امامِ منتظر علیہ السلام ظہور فرما کر عدلِ کامل کا نظام قائم کریں گے۔ایسی مدنی ریاست کا خاکہ، جسے ہم اسلامی تناظر میں پیش کرتے ہیں، شورىٰ، عدل، آزادی، حقوق کے تحفظ، اور اخلاقی اقدار جیسے بنیادی اصولوں پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ اصول ایک ایسے نظام کے تحت بآسانی نافذ کیے جا سکتے ہیں جسے اسلامی مدنی نظام کہا جائے، جو معاشرے کے تمام طبقات کو فیصلہ سازی میں مساوی شرکت کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ، یہ نظام دینی اور مدنی اداروں کے درمیان باہمی تعاون کی فضا قائم کرتا ہے، تاکہ امت کو اس کے اجتماعی و مشترکہ اہداف کی جانب مؤثر طریقے سے رہنمائی فراہم کی جا سکے۔
دورِ مرجعیتِ دینی اس تناظر میں اپنی اہمیت کو برقرار رکھتی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف فکری و شرعی رہنمائی فراہم کرتی ہے بلکہ اسلامی اقدار اور اصولوں کی پاسداری کے لیے امت کی اجتماعی استحکام کو یقینی بناتی ہے۔ مرجعیت کا یہ کردار کسی بھی اسلامی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، جو افراد اور حکومت کو اسلامی اصولوں کے مطابق رہنمائی فراہم کرتا ہے اور ان کی معاشرتی ذمہ داریوں کا شعور بیدار کرتا ہے۔اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرجعیت کی رہنمائی ہر دور کی سیاسی و اقتصادی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اجتہاد کی بنیاد پر جاری رہ سکتی ہے، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرجعیت کسی ایک مخصوص سیاسی ماڈل کو تسلیم کرنے یا اس پر عمل کرنے پر زور دے۔ بلکہ، مرجعیت اس بات کی حامی ہے کہ سیاسی و انتظامی ڈھانچے امت کی فلاح اور شریعت کی اساس پر استوار ہوں، اور ہر نظام کو اس کے مقامی و زمانی حالات کے مطابق ترتیب دیا جائے۔
خلاصہ کلام ؛ غیبت کے دور میں اسلامی مدنی ریاست کے تصور کا مقصد ایک ایسا لچکدار نظام قائم کرنا ہے جو روحِ اسلام کی عکاسی کرتا ہو ۔ یہ نظام حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اسلامی اصولوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرتا۔ یہ مدنی ریاست اسلامی امت کے اتحاد اور باہمی تعاون کی علامت ہوگی، جس کا مقصد ایک جدید اسلامی معاشرے کا قیام ہے جو اسلام کی عظیم قدروں کو اجاگر کرے۔ ساتھ ہی، یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیاری کرے گی، جو دنیا میں عدل قائم کریں گے اور اسلامی حکمرانی کے مکمل وژن کو عملی طور پر نافذ کریں گے۔


