
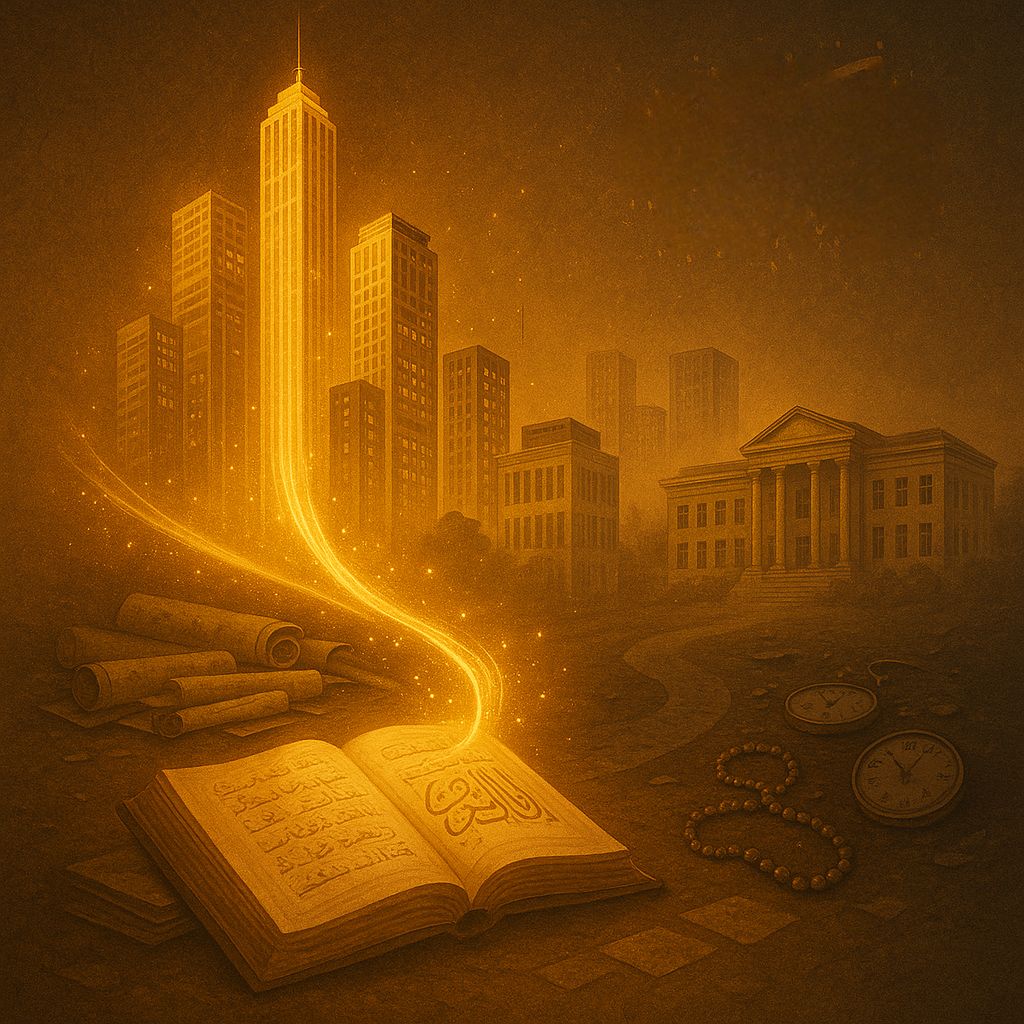
ترقی کے اصول اور شناخت کا سوال: مغرب کیوں آگے بڑھا اور مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے؟
الشيخ معتصم السيد أحمد
جب انسان مغربی دنیا کی شاندار ترقی پر غور کرتا ہےجو ٹیکنالوجی سے لے کر سائنس تک اور سیاسی نظم و نسق سے لے کر حقوق و آزادیوں کے تحفظ تک پھیلی ہوئی ہے تو ذہن میں حیران کردینے والے سوالات جنم لیتے ہیں: آخر یہ معاشرے اس اعلیٰ ترقی تک کیسے پہنچ گئے؟ حالانکہ وہ زیادہ تر ہماری طرح اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ دینی شناخت پر ہماری طرح اصرار کرتے ہیں۔
سوال یہ ہے کہ مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے حالانکہ ان کے پاس تو وہ دین ہے جسے آسمانی وحی اور انسانیت کے لیے ہدایت سمجھا جاتا ہے؟ کیا ترقی و بیداری ایمان سے مشروط ہے؟ اگر ہاں تو پھر وہ اثرات ان معاشروں میں کیوں ظاہر نہیں ہوئے جو بظاہر اسلام کے پیروکار ہیں؟ اور اگر نہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی ترقی کے منصوبوں میں دین کا منصوبہ کمزور ہے؟"
یہ سوالات بہت اہم ہیں یہ درحقیقت ایک اہم مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں جو ایمان اور عمل، عقیدہ اور تہذیب اور خدائی سنن اور تاریخی واقعیت کے درمیان تعلق کو سمجھنے سے متعلق ہے۔ ان کے جواب کے لیے صرف کسی آیت کا حوالہ دینا یا نعرہ لگانا کافی نہیں؛ بلکہ ضروری ہے کہ اُن تہذیبی سنن کو اچھی طرح سمجھا جائے جو اقوام کے عروج و زوال کا باعث بنتی ہیں اور حقیقی تجربات کا تجزیہ قرآنی آیات کی روشنی میں کیا جائے۔
مغرب کی ترقی: اندرونی تبدیلی کا نتیجہ
یورپ میں جو کچھ عصرِ نشاۃ ثانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے وہ نہ تو کوئی اچانک تھا اور نہ ہی عارضی سیاسی فیصلوں کا نتیجہ تھا بلکہ یہ مغربی انسان کی ذہنی اور ثقافتی ساخت میں ایک تدریجی تبدیلی کا پھل تھا جو بارہویں صدی سے شروع ہوئی تھی۔ مذہبی اصلاحی تحریکوں، سائنسی انقلابات اور جغرافیائی دریافتوں کے ذریعے بتدریج پروان چڑھی یہاں تک کہ ایک نئے تہذیبی ماڈل کی صورت میں ظاہر ہوئی جو فعال انسان، تخلیقی عقل اور مؤثر ادارہ جاتی نظام پر قائم تھی۔
یہ درست ہے کہ اس تبدیلی کا زمانہ کلیسا کی طاقت کے زوال اور بتدریج دین کو عوامی دائرے سے الگ کرنے کے ساتھ ساتھ آیا لیکن نشاۃ ثانیہ کو صرف "سیکولرازم" تک محدود کر دینا ایک سطحی بات ہو گی۔ اصل نکتہ صرف یہ نہیں تھا کہ دین کو الگ کیا گیا یا نہیں بلکہ یہ تھا کہ یورپی انسان نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی: اس نے نئی طرزِ فکر اپنائی، اپنے تعلقات کو منظم کیا، علم کو بروئے کار لایا، ادارے قائم کیےاور کام، تحقیق اور اجتہاد کے قوانین کا احترام کیا۔ اس نے گویا انسان کے اندر ایک انقلاب برپا کیااور اسی کے نتیجے میں بیرونی دنیا میں تبدیلی واقع ہوئی۔
اسلام: انسانی بیداری و ترقی کا محرک
دلچسپ تضاد یہ ہے کہ جدید مغربی ماڈل باوجود اس کے کہ وہ دین سے علیحدگی کا دعویٰ کرتا ہے اپنی بہت سی قدروں اور عملی تجربات میں تہذیبی پہلو سے اسلامی روح کے قریب ہے۔ اسلام عقل کی مخالفت نہیں کرتا، علم کو نظرانداز نہیں کرتا اور نہ ہی ریاست و اداروں کی تعمیر سے روکتا ہےبلکہ یہ ایک ایسا دین ہے جو زمین کی آبادکاری کی دعوت دیتا ہے، سوچ بچار پر ابھارتا ہے، نظام و اجتہاد پر زور دیتا ہے۔ قرآن خود تبدیلی کے قوانین کے بارے میں ایک واضح اصول بیان کرتا ہے جب کہتا ہے: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ)(سورہ رعد ۱۱)
اللہ کسی قوم کا حال یقینا اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے
یہ آیت کوئی جادوئی وعدہ نہیں ہے کہ فوری طور پر تبدیلی آ جائے گی اور نہ ہی یہ تبدیلی ایمان سے جڑی چیز ہے جس میں ایمان شرط ہے۔یہ ایک ہمہ گیر کائناتی قانون کی وضاحت ہے: اللہ کسی بھی معاشرے میں اُس وقت تک تہذیبی تبدیلی پیدا نہیں کرتا جب تک وہ معاشرہ خود اپنی اصلاح کے لیے قدم نہ اٹھائے، اپنی سوچ کے انداز کو نہ بدلے اور اپنی اندرونی صلاحیتوں کو نہ بنائے۔ صرف ایمان، عمل، عقل اور نظام کے بغیر، تہذیب نہیں بناتابالکل اسی طرح جیسے قدرتی دولت کا ہونا مگر صحیح انتظام نہ ہونا ترقی نہیں لا سکتا۔
یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ مغرب کا تجربہ، دین کے خلاف کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی قرآن کی تردید ہے۔یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ جو بھی قوم بیداری اور ترقی کے اسباب اختیار کرتی ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں چاہے وہ مذہبی نہ بھی ہو۔ اس کے برعکس جو ان اسباب کو چھوڑ دے اور صرف دعاؤں پر تکیہ کرے یا ماضی کے کارناموں پر بھروسہ کرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی چاہے وہ دن رات دین کے نعرے ہی کیوں نہ لگاتا رہے۔
عصر حاضر میں دینداری کا بحران: جب ایمان عمل سے کٹ جائے
ہمارے بہت سے اسلامی معاشروں میں مسئلہ ایمان کی غیر موجودگی نہیں ہے بلکہ ایمان کا تہذیبی عمل سے کٹ جانا ہے۔ دین بعض لوگوں کے نزدیک محض ایک الگ تھلگ عبادتی نظام بن کر رہ گیا ہےیا پھر ایسا دفاعی نظام جس میں پسماندگی کو قضا و قدر کے نام پر جواز فراہم کیا جاتا ہے، ایمان کو تخلیقی قدروں میں نہیں ڈھالا جاتا: جیسے نظم و ضبط، سائنسی تحقیق، وقت کی پابندی اداروں کی تعمیر اور دنیا سے مثبت تعلق وغیرہ۔
اسی لیے جب یہ آیتِ کریمہ گفتگو میں پیش کی جاتی ہے تو بعض لوگ اسے سطحی انداز میں لیتے ہیں جو نہ انسان کے باطن تک پہنچتی ہے اور نہ ہی معاشرے کی گہرائی کو جانچتی ہے۔ مطلوبہ تبدیلی صرف انفرادی گناہوں سے توبہ تک محدود نہیں بلکہ اجتماعی شعور کی از سرِ نو تشکیل، تہذیبی سستی سے نجات، فکری وابستگی سے بلند ہونااور زندگی کے ہر میدان میں پہل کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا ہے۔
عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے: "مغرب اس لیے ترقی کر گیا کہ اس نے دین کو چھوڑ دیا اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔" یہ دعویٰ یورپ کے دینی تجربے کی حقیقت کو نظرانداز کرتا ہےجو صدیوں تک مذہبی استبداد اور کلیسا کے علم، سیاست اور معیشت پر گرفت سے عبارت رہا۔ اس کے برعکس، اسلام اپنی اصل میں کبھی بھی علم کا دشمن یا آزادی کی راہ میں رکاوٹ نہیں رہا بلکہ اس نے ایک ایسی سائنسی اور انسانی تہذیب کی بنیاد رکھی جسے دنیا نے تسلیم کیا اور جو ترجمے اور تہذیبی روابط کے ذریعے مغربی نشاۃ ثانیہ کو ترقی دینے کا سبب بنا۔
فرق یہ ہے کہ مغرب نے اپنے تجربے کا اندرونی تنقیدی جائزہ لیا اور اس سے ایک نیا نمونہِ عمل اخذ کیا جبکہ مسلمانوں نے اپنے تجربے کا ویسا جائزہ نہیں لیا جیسا لینا چاہیے تھا۔ وہ یا تو ماضی کی جامد تقدیس پر رک گئے یا پھر مغرب کی اندھی تقلید پر اَٹک گئے۔اس کے بغیر کہ ایک مکمل اور ہم آہنگ منصوبہ تشکیل دیں جو اسلام پر بطور ایک تہذیبی نظام اعتماد کے ساتھ عصرِ حاضر کے ساتھ چل سکے۔
حقیقی تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟
تبدیلی باہر سے نہیں آتی، نہ ہی صرف سیاسی نظاموں سے جنم لیتی ہے بلکہ اس کی شروعات انسان کے اپنے اندر سے ہوتی ہے: اس کی سوچ سے، اس کے رویّے سے، اس کے اپنے آپ اور دنیا کے بارے میں نقطۂ نظر سے ملتی ہے۔ اسلام سستی کو معجزوں سے پورا نہیں کرتا، نہ ہی کھوکھلے وعدے دیتا ہے بلکہ کہتا ہے: پہلے تم خود آغاز کرو، اپنی ذات کو بدل لو، تمہارا ماحول اور حقیقت بھی بدل جائے گی۔
اسی لیے مسلمانوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوا وہ خوداعتمادی کا فقدان اور مغرب کے سامنے کمتر ہونے کا احساس ہے؛ جیسے ہم اپنی تہذیب خود پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں اور گویا اسلام کسی نئی بیداری کی بنیاد بننے کے لائق نہیں رہا۔ حقیقت میں یہ استعمار کے فکری اور ثقافتی اثرات کے سب سے خطرناک نتائج میں سے ایک ہے جس نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا کہ ہم بغیر تنقید کے ماڈل درآمد کرتے ہیں، تخلیق کی بجائے صرف تقلید کرتے ہیں اور جدیدیت کا صرف ظاہری لبادہ اوڑھتے ہیں، جس میں اس کی روح نہیں ہوتی۔
لہٰذا حل نہ تو مغرب کی نقالی میں ہے اور نہ ہی فقط ماضی کو دہرانے میں ہے۔حل ایک متوازن تہذیبی منصوبہ بنانے میں ہے جس میں ایمان اور عقل، قدریں اور عمل، روح اور مادہ سب یکجا ہوں۔ ایسا منصوبہ جو اسلام کو ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بلکہ بیداری کے محرک کے طور پر اس کا اصل کردار واپس دلائےاور مسلمان انسان کو اپنی ذات اور اپنی صلاحیت پر دوبارہ اعتماد عطا کرے کہ وہ ایک مختلف ماڈل تشکیل دے سکے کہ انسان دوست، عادلانہ، تخلیقی اور اپنی قدروں سے جڑا ہوا ہو۔
اس کے لیے لازم ہے کہ تعلیم کی اصلاح کی جائے، عقل کو آزاد کیا جائے، ایسے ادارے تعمیر کیے جائیں جو قابلیت کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ابتکار و جدّت کی روح کو پروان چڑھایا جائے اور دین کو زندگی کے ساتھ جوڑا جائے نہ کہ اسے حقیقت سے الگ کر دیا جائے۔ وہ دین جو نہ باعمل اور کارآمد انسان پیدا کرے، نہ بگڑے ہوئے رویے کو درست کرے اور نہ ہی سوئے ہوئے شعور کو بیدار کرے، وہ بیداری و ترقی کے لیے سہارا نہیں بلکہ بوجھ بن جاتا ہے۔
خاتمہ
مندرجہ بالا بحث کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ مغرب کی ترقی قرآنِ کریم کی اس آیت:
(إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ)(سورہ رعد ۱۱)
اللہ کسی قوم کا حال یقینا اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے
کے خلاف نہیں بلکہ اس کی ایک عملی تصویر ہے۔ مسلمانوں کی پسماندگی کی وجہ ان کا دین سے وابستہ رہنا نہیں بلکہ دین کو زندگی سے الگ کر دینا اور اس کی اقدار کو تبدیلی کی محرک قوت کے طور پر بروئے کار نہ لا سکنا ہے۔ لہٰذا اصل سوال یہ نہیں کہ مغرب کیوں ترقی کر گیا؟ بلکہ یہ ہے کہ مسلمان کب دوبارہ اٹھیں گے؟ اور وہ اپنے اندر کیا تبدیلی لائیں گے تاکہ ان کے حالات بدل سکیں؟
یہی دراصل اصل مسئلے کا نچوڑ اور آئندہ تہذیبی بیداری کی کنجی ہے۔


