
| احکامِ اجتماعی | اسلامی فکر کی تجدید: ابدی اقدار اور بدلتے حالات کے درمیان
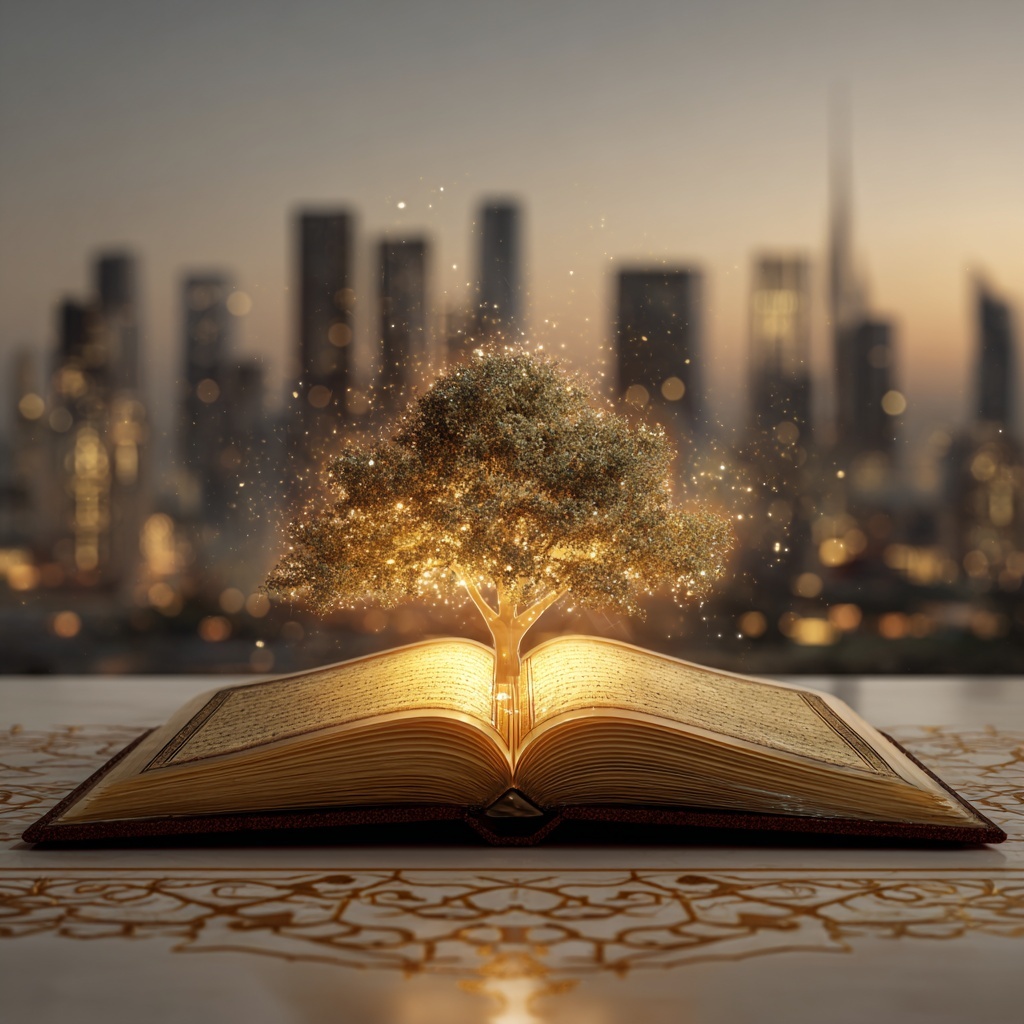
اسلامی فکر کی تجدید: ابدی اقدار اور بدلتے حالات کے درمیان
الشيخ معتصم السيد أحمد
معاصر فکری و ثقافتی میدان میں "اسلامی فکر کی تجدید" کا مسئلہ بار بار زیرِ بحث آتا ہے۔ آج کوئی بھی دینی گفتگو اس بحث سے خالی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ یہ بعض اوقات یہ ایک الزام بن جاتا ہے اور بعض اوقات ایک ناگزیر ضرورت۔ مگر سوال یہ ہے کہ تجدید سے مراد کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب تراث (ورثے) کو منسوخ کر دینا ہے؟ یا احکام کو بدل دینا؟ یا یہ خود دین کی ایک نئی تفہیم کی دعوت ہے؟ تجدید کا تعلق زمان و مکان سے کس قدر ہے ؟ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کی حدود و ضوابط کیا ہیں؟
اگر ہم قرآن اور سنت کے تناظر میں تجدید کے مفہوم کو دیکھیں تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام ایک جاوداں دین ہے۔ اس کی ہر زمان و مکان میں ہدایت کی صلاحیت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے تمام احکام جامد اور غیر قابل تبدیل ہیں، بلکہ اس میں اقدار کے ثابت رہنے کے ساتھ ساتھ نفاذ میں حرکت، فہم میں تازگی اورزمان و مکان کی تغیر پذیری کے ساتھ مسلسل تعامل کی آمادگی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا تجدید کا مطلب دین کے جوہر اور اس کے اصولی ثوابت کو چھیڑے بغیر اسلامی خطاب کو انسانی زندگی کے متغیر حالات کے ہم آھنگ بنانا ہے ۔ دقیق الفاظ میں کہا جائے تو تجدید کا مطلب یہ ہے کہ دینی فہم کے ذرائع کو اس طرح متحرک کیا جائے کہ وہ حالاتِ حاضرہ کے ساتھ ہم آہنگ رہیں، نہ یہ کہ خود نصوص کو ہی اس انداز میں بگاڑا جائے کہ وہ واقعات کے زیر اثر آجائیں ۔
پس تجدید عقل کو وحی کے دائرے میں استعمال کرنے کا نام ہے، اور ابدی اقدار کو بدلتی ہوئی انسانی ضروریات میں روشنی کے لئے حاضر رکھنے کا عمل ہے۔ اسلام کسی جامد و بے جان مذہب کے طور پر نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک زندہ پیغام ہے زمانوں کے ملبے تلے دبے بغیر زمانوں کو عبور کرتا ہے۔
عقل اور وحی: تکامل کا رشتہ، نہ کہ تضاد
اسلام کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے عقل اور وحی کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا بلکہ ان دونوں کے درمیان تکمیلی تعلق قائم کیا۔ وحی الٰہی اقدار اور بڑی حقائق کا ماخذ ہے، جبکہ عقل وہ وسیلہ ہے جو حقیقتِ واقعہ کو دریافت کرتی ہے اور اس کو وحی کی اقدار کے ساتھ جوڑتی ہے۔ نہ وحی اپنے مقصود کو عقل کے بغیر پورا کر سکتی ہے، اور نہ عقل وحی کی ہدایت کے بغیر حق تک پہنچ سکتی ہے۔ پس اگر ہم تجدید کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی کنجی "عقل" ہے۔ لیکن یہ کوئی بے لگام ہر قید سے آزاد عقل نہیں، بلکہ اقدار کی تابع عقل۔ ایسی عقل جو شریعت کی روح سے باہر حرکت نہ کرے، بلکہ اسی کے دائرے کے اندر رہ کر ہر دور میں "بہترین بات" کو دریافت کرے اور "بہترین عمل" کو وجود میں لائے۔
اسلامی شریعت خود عقل کو فکری قیادت کے مقام پر رکھتی ہے، اور اسے بار بار تدبر، تعقل اور تفکر کی دعوت دیتی ہے۔ عقل کو محض نصوص کا آلہ کار یا اندھا تابع نہیں بنایا گیا، بلکہ اسے احکام کے استنباط، حالات کے فہم، اور نص کو ظرفِ زمان و مکان کے ساتھ جوڑنے میں ایک بنیادی شریک قرار دیا گیا ہے۔ اسلام انسان کو ایک بے اختیار موجود کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ اسے ایک فعال اور بااختیار وجود مانتا ہے جو اپنے فیصلوں اور انتخاب کا ذمہ دار ہے۔ اسی لیے عقل کو تکلیف کا معیار بنایا گیا، اور فقہاء نے ہر عبادتی عمل میں عقل کو شرط قرار دیا، کیونکہ دین کی سمجھ عقل کے بغیر ممکن نہیں۔ بلکہ اسلامی شریعت کی گہرائی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ عقل کو صرف فہم کا ذریعہ نہیں بناتی، بلکہ اسے بدلتے ہوئے حالات اور زمان و مکان کے مطابق مصالح و مفاسد کی دریافت کی ذمہ داری بھی دیتی ہے۔ یہ ذمہ داری شریعت مقدسہ کے مقاصد کے اسی فریم ورک میں رہتے ہوئے دی جاتی ہے کہ جو نصوص کو ان مقدس اقدار کے ساتھ توازن میں رکھتا ہے جو رسالت کے ذریعے سامنے آئے ہیں۔ کیونکہ مصلحت دین سے کوئی الگ شے نہیں بلکہ اس کے ڈھانچے کا حصہ ہے، اور عقل در حقیقت وحی کی دشمن نہیں بلکہ اس کا میدانِ عمل ہے۔
اسی لیے اسلام عقل کی حرکت کو جامد نصوص کی دیواروں پر معطل نہیں کرتا، نہ ہی اسے ماضی کے فہم کے ساتھ منجمد کر دیتا ہے، بلکہ اسے وحی کی روشنی میں زندگی کے ساتھ فعال ہونے پر آمادہ کرتا ہے۔ عقل کو اجتہاد کی امانت دیتا ہے، اور ایسے وسائل و طریقوں کی تجدید کی ذمہ داری سونپتا ہے جو شریعت کے اعلیٰ مقاصد سے ہم آہنگ ہوں۔ یوں تجدید محض حالات کے دباؤ کے جواب میں جدیدیت کے ساتھ چلنے کی کوشش نہیں بلکہ اسلام کی اپنی فطرت سے ابھرنے والی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ یہ دین کی زندہ روح کا تسلسل ہے جو اسلام کو ایک ایسا پیغام بناتی ہے جو اپنی شناخت کھوئے اور اپنے مقاصد سے جدا ہوئے بغیر انسان اور اس کے زمانے کے ساتھ متحرک رہتا ہے ۔
بعض اوقات یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ تجدید ایک ایسی ضرورت ہے جسے معاصر حالات نے مسلط کیا ہے، یا یہ کہ یہ ایک فکری عیاشی ہے جسے ہم نے مغربی تہذیب کے دباؤ میں آکر قبول کر لیا ہے ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں تجدید نہ کوئی حادثاتی چیز ہے اور نہ ہی کوئی بیرونی عنصر، بلکہ یہ خود پیغامِ خاتم کی منطق کا حصہ ہے۔ وہ دین جسے ہر زمان و مکان کے لیے کارآمد اور مفید مانا گیا ہے، لازماً اپنی ساخت میں ایسا پہلو رکھتا ہے جو اسے ہر دور میں تجدید کے قابل بنائے۔
یہ مفہوم قرآن کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے جو صرف عقل کے استعمال پر ہی نہیں بلکہ "احسن کی پیروی" کو ایک منهج کے طور پر پیش کرتی ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾
"جو لوگ سنتے ہیں بات کو تو پیروی کرتے ہیں اس کی جو سب سے بہتر ہے۔"(الزمر: 18)
اور فرمایا: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کریں جو سب سے بہتر ہو (الاسراء : 53)
قرآن نے ہمیں صرف اچھے قول کی پیروی کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ "سب سے اچھے" کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عقل میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بہتر اور بہترین میں فرق کر سکے۔ اسی لیے قرآن نے عقل کے سامنے یہ دروازہ کھولا کہ وہ اقوال و افعال میں موازنہ کرے اور بدلتے حالات کے مطابق اصلح کو منتخب کرے، بشرطیکہ یہ سب دین کے ثوابت سے باہر نہ ہو۔ ان آیات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حقیقی مومن وہ ہے جو پہلے اچھی طرح سننے کا ہنر رکھتا ہو، پھر بہترین انتخاب کرنے کا شعور بھی۔ اور یہ "بہترین" زمان و مکان، مصلحت اور انسانی حالات کے تغیر کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔
ہم اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں دیکھتے ہیں: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ درگزر کو اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو (الاعراف : 199)
یقیناً معلوم ہے کہ "عرف" کوئی جامد چیز نہیں، بلکہ وہ ہے جس پر لوگ اپنے زمان و مکان کے سیاق میں بھلائی کے طور پر متفق ہوں، جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اسی لیے بہت سے فقہاء نے عرف کو احکام کے فہم میں ایک اہم ماخذ قرار دیا ہے، کیونکہ یہ امت کی "متغیر اجتماعی عقل" کی نمائندگی کرتا ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ... يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾
"وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے" (الجمعہ :2)
یہاں "حکمت" کا مطلب صرف نصوص کا علم نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ باشعور طریقے سے معاملہ کرنے کی صلاحیت، ان کو واقعے سے مربوط کرنے، اور نئے حالات کے مطابق ان سے احکام اخذ کرنے کی اہلیت بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ "حکمت" ہی دراصل انسان کی خلافت اور اس کی زندگی کے مسلسل نظم و نسق کا حقیقی راز ہے۔
معرفتی بتوں کو توڑنا۔ تجدید کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ فکری شجاعت ہے، تاکہ ان چیزوں کو توڑا جا سکے جنہیں قرآن نے "رسم و رواج کے بت" کہا ہے؛ جیسے باپ دادا کی اندھی تقلید، معاشرے کا خوف، یا حکمران طاقتوں کی غلامی۔ دراصل عقل کی بیداری اور شعور کی آزادی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جہالت نہیں بلکہ وہ جھوٹی تقدیس ہے جو ماضی یا بگڑے ہوئے حال کو دی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے ان بتوں کے خلاف طویل جدوجہد کی، کیونکہ یہ ہمیشہ سے انسان کے فکری اور دینی آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ رہے ہیں
مثال کے طور پر، دعوت نبوی کو جھٹلانے والوں کا بہانہ رسول اللہ کی دلیل میں کسی کمزوری یا پیغام کی ابہام پر مبنی نہیں تھا، بلکہ وہ حقیقتاً اس خوف میں مبتلا تھے کہ کہیں ان کا پرانا نظام ٹوٹ نہ جائے اور مانوس ماحول ختم نہ ہو جائے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے: ﴿إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا﴾ اگر ہم تیرے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی سرزمین سے اچک لیے جائیں گے"(القصص: 57)
یعنی یہ جواز ایک ایسی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے جو موجودہ صورتِ حال کو ناقابلِ ترک قلعہ سمجھتی ہے، چاہے وہ صورتِ حال ظالمانہ اور پسماندہ ہی کیوں نہ ہو۔ معاشرے کا خوف، مفادات کے ختم ہونے کا اندیشہ، یا غالب دھاروں سے ٹکرا جانے کی جھجک—یہ سب وہ بت ہیں جن سے قرآن خبردار کرتا ہے، کیونکہ یہ حق کو عقل کے ترازو کی بجائے طاقت کے ترازو سے تولنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن نے سیاسی استبداد کو بھی بے نقاب کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ کس طرح عوام کے شعور کو مفلوج کرتا ہے، جیسا کہ فرعون کے بارے میں ارشاد ہے: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ پس اُس (فرعون) نے اپنی قوم کو ہلکا جانا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ بے شک وہ لوگ فاسق تھے"(الزخرف: 54)
طغیان کے لیے بہت زیادہ ذہانت درکار نہیں ہوتی بلکہ عوام کے اندر بزدلی کی ضرورت ہوتی ہے۔جب عوام اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ امن، رسم یا قیادت کے نام پر غلام بنائے جائیں اور کر دئے جائیں ۔ یہ آیت دراصل طغیان کے ڈھانچے کو بے نقاب کرتی ہے: یعنی شعور کی تحریف اور جہالت پر سرمایہ کاری۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ حالات کو تقدیس دینے کی سب سے نمایاں صورت یہ ہے کہ تراث (ورثہ) کو تحقیق اور عقل کے ترازو میں تولے بغیر ہی تھامے رکھا جائے، اور جسے "سلفِ امت" کہا جاتا ہے، ان کی باتوں کو ان کے تاریخی پس منظر اور متغیر حالات کے بغیر مقدس مان لیا جائے۔ قرآن نے اس بیمارانہ وابستگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾
اور اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے کہ ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر اور ہم انہی کے نقشِ قدم پر چلنے والے ہیں (الزخرف: 23)
یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح تقلید عقیدہ بن جاتی ہے اور جمود ایک اصول۔ لیکن قرآن ان سے کی مذمت کرتا ہے اور کہتا ہے: ﴿قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾
کہا: کیا (تم پیروی کرو گے) اگرچہ میں لایا ہوں تمہارے پاس اس سے زیادہ سیدھی راہ کی طرف (بات) جو تم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا ہے؟ (زخرف: 24)
یعنی حقیقی ہدایت بسا اوقات موروثی چیزوں کو دہرانے میں نہیں بلکہ انہیں توڑنے میں مضمر ہوتی ہے۔ چنانچہ تجدید اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم ماضی کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، حال سے خوفزدہ ہونا ترک کر دیں، اور اس کا جائزہ لیں؛ جو چیز تحلیل کی محتاج ہے اسے تحلیل کریں اور جو چیز آج بھی کارآمد اور محرّک ہے اسے باقی رکھیں۔ ماضی معصوم نہیں، معاشرہ حقیقت میں مرجع نہیں، اور اقتدار شعور کا وصی نہیں۔ اسی لیے تجدید کی معرکہ آرائی دراصل شعور کی آزادی کی جنگ ہے، اور ان معرفتی بتوں کے انہدام کی جدوجہد ہے جو خوف، تقلید اور استبداد کی وجہ سے اسلامی ثقافت میں جمع ہو گئے۔ اس سب کے مقابلے میں یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ تجدید کا مطلب بے لگامی نہیں، نہ ہی دین کے ثوابت کو توڑنا، اور نہ ہی وحی کے نصوص سے کھیلنا، چاہے اس پر "جدیدیت" کا لیبل لگا دیا جائے۔ بلکہ اسلام میں تجدید تین بنیادی دائرہ بندیوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے:
1- قرآنی اقدار کا ثبات: جیسے عدل، توحید، کرامت، آزادی، تکافل… اور ساتھ ہی اس کی عبادتی پیلو
2- فہم کا مقاصدِ شریعت کے ساتھ ہم آہنگ ہونا: یعنی نص کو اس کے بڑے اہداف کے تحت سمجھنا، نہ کہ صرف جزوی ڈھانچوں میں مقید کرنا۔
3- عقل سلیم کا حوالہ، نہ کہ بے لگام خواہش کا: اس عقل کو شراکت دار بنایا جائے جو وحی کی روشنی میں فہم کی راہ ہموار کرے، نہ کہ مطلق العنان حاکم بن کر اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کرے۔
آخر میں، ہم مبالغہ نہیں ہوگا اگرہم یہ کہیں کہ تجدید محض وقتی ضرورت یا وقت کے دباؤ کا نتیجہ نہیں، بلکہ خود دین کے زندہ رہنے کی بنیادی شرط ہے۔ وہ دین جو تجدید نہ کرے، مر جاتا ہے، اور وہ شریعت جو زندگی کے تناظر میں نہ سمجھی جائے، محض رسمی اور بے روح رسوم میں بدل جاتی ہے۔ اسی لیے حقیقی تجدید فکری عیاشی نہیں بلکہ اسلام کی فطرت کا حصہ ہے، کیونکہ یہ دین خاتم ہے جو ہر زمانے کے انسان کو مخاطب کرتا ہے، اسے عقل کی روشنی میں حق کی طرف لے جاتا ہے، اور زندگی کے راستوں میں اپنی ابدی اقدار سے رہنمائی کرتا ہے۔
بالآخر تجدید، اسلام کی روح کے ساتھ وفاداری ہے نہ کہ اس کے نصوص سے بے وفائی۔ یہ پیغام کی حیات مندی کا اظہار ہے، نہ کہ اس کے جوہر سے غفلت۔ اور اگر ہم اسے درست طور پر بروئے کار لائیں تو یہ دین سے بغاوت کا باعث نہیں بلکہ اس کی طرف زیادہ بیداری اور گہرے شعور کے ساتھ واپسی کا ذریعہ ہوگا۔


