
| قرآن کریم کا متن | دینی متن: روایت اور جدیدیت کی فکری کشمکش
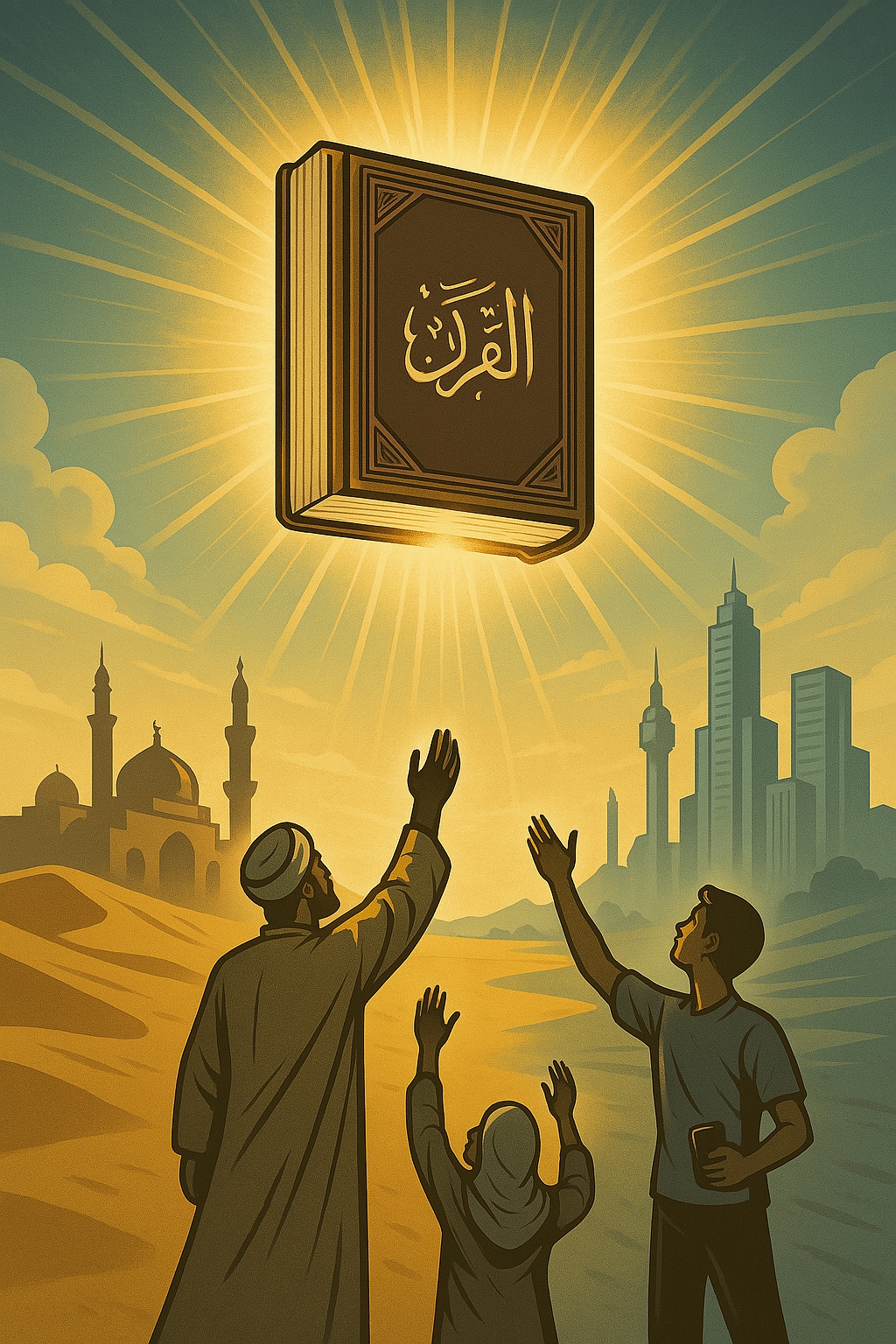
دینی متن: روایت اور جدیدیت کی فکری کشمکش
شيخ معتصم السيد احمد
(ترقی پسند اسلام)یا (تجدیدِ دینی)جیسی اصطلاحات دراصل اسلامی فکر کے اُس رجحان کے مقابل ایک ایسے فکری موقف کی نمائندگی کرتی ہیں جو قدامت پسندی اور جمود کار فہم کی آئینہ دار ہے۔ یہ رجحان اس تصور پر قائم ہے کہ اسلام کی تفہیم محض اُن معانی اور تشریحات تک محدود ہے جو ماضی میں وضع کی گئی تھیں، اور ان معانی کی بازیافت ہی دین کو سمجھنے کا واحد معتبر طریقہ ہے۔ تاہم، اس موقف میں ایک اہم خامی یہ ہے کہ یہ انسانی معاشرے کی مسلسل تغیر پذیر حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے۔ اس کے باوصف کہ عصرِ حاضر کی پیچیدہ علمی، سماجی، اور قانونی تبدیلیاں ایسے ایسےنئے سوالات اور مسائل پیدا کر رہی ہیں جن کا حل محض ماضی کی تفہیم کے دائرے میں تلاش کرنا ممکن نہیں اور ان چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کے لیے اجتہادی بصیرت اور فکری تجدید ناگزیر ہے۔
چنانچہ "ترقی پسند اسلام" یا " تجدیدِ دین" کا بیانیہ اس ضرورت پر زور دیتا ہے کہ اسلامی علوم کی تعبیر نو کی جائے ۔ ایک ایسی تعبیر جو اسلامی اصولوں پاسداری کرتے ہوئے معاصر تناظرات اور انسان کے بدلتے ہوئے حالات سے موثر طور پر ہم آہنگ ہو۔ اس زاویۂ نظر کا مقصد اسلام کو محض ماضی کی یادگار بنانے کی بجائے ایک ایسے زندہ اور متحرک دین کے طور پر برقرار رکھنا ہے جو ہر زمانے کے تقاضوں کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔تاہم، اگر ہماس معاملے کا بنظر عمیق جائزہ لیں تو واضح ہوتا ہے کہ ان دونوں رجحانات (یعنی ماضی کی طرف رجوع اور جدید دور سے ہم آہنگی کی کوشش) کی اصل پیچیدگی اس تصور میں مضمر ہے کہ اسلام کو خاص تاریخی محور یا "زمانی مرکزیت" کے تناظر میں سمجھا جائے۔ چاہے یہ مرکزیت ماضی پر مرکوز ہو ( جو سلفِ امت کے ماڈل کی بازیافت کی کوشش کرتی ہے ) یا حال پر (جو اسلام کو جدید تغیرات سے ہم آہنگ بنانے کی سعی کرتی ہے) مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات اور مقاصد نہ تو کسی خاص دور سے وابستہ ہے اور نہ ہی اسلام کی اصل روح وقتی حالات کی تابع بلکہ یہ خود وقت اور حالات کو اپنی اقدار کے تابع بنانے کی دعوت دیتی ہے۔ اسلام ایک مکمل اور دائمی نظامِ حیات ہے، جو ایسی بنیادی اقدار اور اصول پیش کرتا ہے جو ہر زمانے اور ہر جگہ پر یکساں اطلاق کے قابل ہیں۔ یہی آفاقیت اسلام کی فکری اور تہذیبی طاقت کی بنیاد ہے۔
اسلام کے فہم کے سلسلے میں جدت پسندوں اور روایت پسندوں (یا قدامت پسندوں) کے مابین پائے جانے والا اختلاف براہِ راست مقدس متون، بالخصوص قرآن مجید، سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف ان متون کی تعبیر و تفہیم کے طریقۂ کار اور ان کے پسِ منظر میں کارفرما فکری زاویوں سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآنِ مجید بذاتِ خود ان متضاد تعبیرات کا موجب نہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا آفاقی اور الٰہی کلام ہے جو زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے۔
قرآن مجید کا خطاب ایک آفاقی اور ہمہ گیر خطاب ہے، جو ہر دور اور ہر مقام میں انسانی شعور سے براہِ راست مکالمہ کرتا ہے۔ اس کی معنویت کسی خاص تاریخی سیاق یا مخصوص زمانی تناظر کی محتاج نہیں، اور نہ ہی اس کے بنیادی مضامین اور مقاصد زمانے کی تبدیلی سے متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کے فہم کو کسی ایک مخصوص تاریخی یا زمانی حوالہ اور ریفرنس سے مشروط کر دینا ایک فکری مغالطہ ہے، کیونکہ اس طرزِ فکر میں وقت کو متن کی تعبیر پر حاکم بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ متن بذاتِ خود زمان و مکان سے بالاتر ایک مستقل الٰہی رہنمائی کا منبع ہے۔ قرآن کی حیثیت سورج کی مانند ہے، جو ہر دور پر اپنی روشنی بکھیرتا ہے، لیکن خود کسی دور کا پابند نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ہر زمانے اور ہر مقام کے لیے اطلاق کےقابل ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہونا چاہیے کہ اسلام ہی وہ معیار فراہم کرتا ہے جس کی روشنی میں زمان و مکان کی تبدیلیوں کو سمجھا جانا چاہئے نہ کہ ہم زمانے کو قرآن کے فہم کا پیمانہ بنا لیں۔
پس،جو لوگ اسلام کو سمجھنے کےلئے تاریخ کو سب سے اہم ذریعہ سمجھتے ہیں، انہوں نے اسلام کا ایک محدود اور پرانا تصور پیش کیا ہے، جو زیادہ تر سلفِ صالحین کے مثالی نمونوں پر مبنی ہے۔ اس وجہ سے وہ اسلام کے اصل مقصد اور روح سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ آج کے بدلتے ہوئے دور اور لوگوں کی موجودہ زندگی کی حقیقتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ان کا فہم ایک ایسا پرانا نمونہ ہے جو آج کے چیلنجز اور ضروریات کا حل پیش کرنے سے قاصر ہے۔
دوسری جانب، وہ افراد جنہوں نے محض عصری سیاق کو اختیار کیا اور اسلام کو جدید ثقافتی حالات کے تابع بنانے کی کوشش کی، انہوں نے دین کی مطلق اور آفاقی معنویت کو رد کر دیا۔ نتیجتاً وہ اسلامی عقائد و اقدار کی بنیادی اساس سے منحرف ہو گئے اور ان کی جگہ ان جدید اقدار کو اپنا لیا جو صرف وقتی تقاضوں پر مبنی ہیں۔اس طرح وہ لوگ اگرچہ زندگی کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے میں تو کامیاب ہوئے، تاہم اسلام کے اصل پیغام سے دور ہو گئے، اور یوں اسلام کی غیر متبدل بنیادوں اور متغیر حالات کے درمیان توازن قائم رکھنے میں ناکام رہے۔
اسلام کی موجودہ دور میں مؤثر موجودگی و نمائندگی اور اس کی حمایت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر قسم کی زمانی مرکزیت سے آزاد ہو جائیں، چاہے وہ ماضی ہو یا حال۔ اسلام کو اس کی ان جامع اور آفاقی اقدار اور معانی کے ذریعے سمجھنا چاہیے جو زمان و مکان کی حدوں سے بالاتر ہوں۔ اسلام کی ہر زمانے اور ہر جگہ افادیت اور مطابقت اسی صورت ممکن ہے جب ہم ان بنیادی اقدار پر توجہ دیں جن کی بدولت قرآنِ مجید تمام انسانوں اور ہر دور کے لیے مؤثر اور زندہ خطاب بن جاتا ہے۔ یہ فہم تبھی ممکن ہے جب یہ سمجھا جائے کہ یہ الٰہی پیغام انسانی فطرت کی بنیادوں اور عقلانی ضروریات سے ربط و ضبط بناتا ہے، جو تمام انسانوں میں مشترک اور غیر متغیر ہیں، چاہے ماحول اور ادوار مختلف ہی کیوں نہہوں۔
جیسا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے انبیاء کی ذمہ داری کا خلاصہ کو یوں بیان فرمایا:
فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه، ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم منسي نعمته، ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول"
"اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ان لوگوں میں بھیجا اور ان کی طرف یکے بعد دیگرے انبیاء بھیجے، تاکہ وہ اپنی فطرت کے اپنے عہد کو پورا کریں، انہیں اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، تبلیغ و ابلاغ کے ذریعے ان پر دلیل قائم کریں، اور ان کے اندر چھپی ہوئی عقل و فہم کے خزانے جگائیں۔"
اسی وجہ سے قرآن ایک کتابِ ذکر و تذکرہ ہے، نہ کہ محض معلومات کا ایسا مجموعہ جو زمان و مکان کے بدلتے ہوئے حالات کے تابع ہو۔امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:"اللہ تعالیٰ کی لوگوں پر دو حجتیں ہیں: ایک ظاہری حجت اور دوسری باطنی حجت۔ ظاہری حجت رسول، انبیاء اور ائمہ علیہم السلام ہیں، اور باطنی حجت عقل ہے۔"
یہ بیان اسلامی معرفت میں وحی اور عقل کے مابین تعلق کی نہایت باریک اور دقیق تفہیم پیش کرتا ہے، اور اس امر پر تاکید کرتا ہے کہ اسلام زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے۔ چونکہ عقل ایک واحد، قطعی اور غیر متغیر معیار ہے، قرآن بھی اسی حیثیت کا حامل ہے۔ اگر عقل وہ معیار ہے جو بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لیتی اور حقیقت کی سمت کو منظم کرتی ہے، تو قرآن بھی ویسا ہی معیار ہے۔ اسی لیے ہم اسلامی معرفت کے دائرے میں ایسی تمام کوششوں کو رد کرتے ہیں جو وحی سے الگ ہوں، اور ایسے نظریات کو بھی مسترد کرتے ہیں جو وحی کو قبول کرتے ہوئے عقل کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں۔
ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ عقل اور وحی کے درمیان ایک جدلیاتی تعلق موجود ہے، اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے بغیرمکمل اور بامعنی نہیں ہو سکتا۔ اس تعلق کی درست تفہیم کے لیے ضروری ہے کہ وحی کو ایک ایسی حقیقت کے طور پر سمجھا جائے جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے؛ کیونکہ جس لمحے وحی کسی مخصوص وقت یا جگہ سے منسلک ہو،پس وہی لمحہ عقل کا وحی سے الگ ہونے کا لمحہ ہوتا ہے۔
لہٰذا اسلام کو ترقی پسند یا پسماندہ قرار دینا صرف اسلامی تحریکوں کی موجودہ صورتحال کی عکاسی ہے، نہ کہ اسلام کے حقیقی مفہوم کی ترجمانی، خواہ وہ مقدس نصوص ہوں جیسے قرآن یا ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات۔ اس لیے نہ وہ روایتی تصور قابلِ قبول ہے جو اسلام کو صرف سلف کے فہم تک محدود کر دیتا ہے، اور نہ ہی وہ تفہیم قابل قبول ہے جو اسلام کے بنیادی اور لازمی اصولوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔
بلا شبہ، سلفیت تہذیبی اور تمدنی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے جسے عبور کرنا ناگزیر ہے۔ اسی طرح، جدیدیت کی انتہا پسندی بھی ایک سنگین رکاوٹ ہے، جو مغرب کی دلدادہ اور شکستہ سوچ کو فروغ دیتی ہے، اور اپنے وجود و حقیقت کو مغربی نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے اپنی اصل اقدار کو مسترد کر چکی ہے، اور انہیں ترقی میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سمجھتی ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اسلام کو اس کی واضح اور فطری روح، اور اس کے بنیادی اصولوں سے محروم کر دیا، اور مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسلام مخالف نظریات کو خود اسلام کے نام پر قبول کر لیں۔ ان کے نزدیک اسلام محض نسلی، قبائلی یا خاندانی وابستگی ہے جسے جدید تمدن کی ضروریات کے مطابق ڈھالا جانا چاہیے۔اس اندازِ فکرکانتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسلام کی سب سے اہم خصوصیت سے محروم ہو گئے ۔ یعنی وہ تخلیقی روح جو زمان و مکان کی تبدیلیوں پر قابو پانے اور خود کو ان کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔"
آخر میں یہ حقیقت واضح ہو جانی چاہیے کہ کوئی 'ترقی پسند اسلام' یا 'رجعت پسند اسلام' وجودہی نہیں رکھتا۔ یہ مسلمان ہی ہوتے ہیں جو خود کو کبھی ترقی پسند کہتے ہیں اور کبھی سلفی یا ماضی پرست۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، وہ تو زندگی کی ایک ہمہ گیر دعوت ہے ۔ ایسی زندگی جو اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ رواں ہو، مگر وحی کی روشنی اور توحید کی بصیرتوں کی بنیاد پر استوار ہو۔ اور اس مقصد کے حصول کے لیے، ہم دو بنیادی اصولوں کی نشان دہی کرتے ہیں:
اوّل: اصولِ اصالت
اس سے مراد ہے کہ اسلام کو اُن تمام تصورات اور خیالات سے پاک کیا جائے جو گمراہ کن اور بگڑی ہوئی ثقافتوں سے ماخوذ ہیں، تاکہ دین اپنی اصل، خالص اور الٰہی صورت میں واپس آجائے ۔ ایک ایسا نظامِ حیات جو اعلیٰ اقدار اور عظیم اصولوں پر مبنی ہو، اور جو انسان کو زندگی کے سفر میں سہارا دے۔یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم براہِ راست اسلامی نصوص کی طرف رجوع کریں، اور اُن سے دل و جان کے ساتھ ایساتعلق قائم کریں جو شکست خوردگی، تعصّب یا نفسیاتی دباؤ سے پاک ہو۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کی الجھنیں اُن پر مسلط نہ کریں، بلکہ خود کو اُن کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔
ثانیاً: اصولِ واقعیت اور کشادہ نظری
اس اصول کا تقاضا ہے کہ ہم زندگی کی ناگزیر حقیقتوں کے ساتھ سنجیدہ، متوازن اور فعّال انداز میں ہم آہنگ ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جدید تہذیب کا گہرا جائزہ لیں، اور اسے اُن منفی اثرات سے پاک کریں جو یورپی انسان کی تنگ نظر سوچ اور محدود زاویۂ نگاہ سے پیدا ہوئے ہیں۔یہ مطالعہ نہ تو اندھی تقلید پر مبنی ہو اور نہ ہی سخت گیر انکار پر، بلکہ یہ عقل کی روشنی اور قرآن کی ہدایت کے تحت ہو۔ ایک ایسا تجزیہ جو تنقیدی شعور اور فکری بصیرت سے مزین ہو۔پھر اسی بنیاد پر، اپنی تہذیبی اصالت سے قوت حاصل کرتے ہوئے ہم ایک ایسی مضبوط اور متوازن اسلامی تہذیب کی تشکیل کریں جو انسان کی روحانی اور مادی ضروریات کو باہم مربوط کر کے اُسے ایک مکمل، ہم آہنگ اور باوقار زندگی عطا کرے۔


